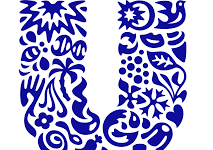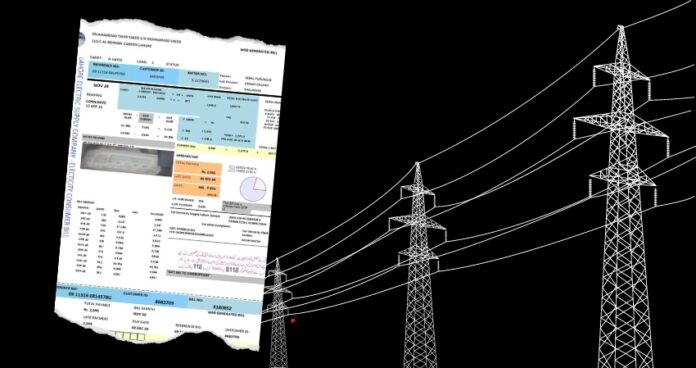پہلی نظر میں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ سٹیفنی کیلٹن اور اسد زمان کی شخصیات میں کوئی قدر مشترک ہے۔ سٹیفنی ایک پرجوش امریکی شہری اور صدارتی امیدوار برنی سینڈرز کی معاشی مشیر ہیں، وہ انتہائی پراعتماد ہونے کے ساتھ سی این بی سی پر تابڑ توڑ پوچھے جانے والے سوالوں کے بلا جھجک جوابات دینے میں ماہر ہیں۔ اسد زمان دانشور نظر آتے ہیں، وہ نہایت مہذب انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور سٹیٹ بینک آف پاکستان میں نہایت تفصیلی اور سنجیدہ پریزنٹیشنز دیتے ہیں۔ اسد زمان پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے ایکسٹرنل رکن ہیں۔ سٹیفنی سرمایہ دارانہ نظام میں اصلاحات کی بات کرتی ہیں جبکہ اسد زمان اسلامی معیشت کے فوائِد گنواتے نہیں تھکتے۔
لیکن ایک نکتہ ایسا بھی ہے جو ان دونوں ماہرین معاشیات میں مشترک ہے: یہ دونوں متنازعہ معاشی نظریے ماڈرن مانیٹری تھیوری (ایم ایم ٹی) کے حامی ہیں۔
ایم ایم ٹی ایک بہترین نظریہ ہے جو گزشتہ دہائی میں ماہرین معاشیات نے پیش کیا تھا، اسے بدترین نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں جس کا دارومدار اس بات پر ہے کہ آپ اس سے متعلق بات کس سے کر رہے ہیں؟ یہ بہت زیادہ امریکا زدہ بھی نظر آتا ہے اور گزشتہ ایک برس کے دوران عالمی منظرنامے پر اس کا غیرمعمولی قبول عام حاصل کرنا اس کی وضاحت کے لیے نہایت اہم ہے۔ سٹیفنی اس تصور کو میڈیا میں زیادہ سے زیادہ فروغ دیتی رہی ہیں۔
بلومبرگ کے مطابق، 2019 میں گوگل پر ایم ایم ٹی کی اصطلاح کی تلاش میں چار گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے جس کی ایک بڑی وجہ سٹیفنی کیلٹن کی جانب سے چلائی جانے والی آگاہی مہم بھی ہے۔ وہ چونکہ برنی سینڈرز کی مشیر بھی ہیں جس کے باعث انہیں امریکی دائیں بازو کے حلقوں میں مثبت پہچان حاصل نہیں ہو پائی اور ظاہر ہے کہ نہایت معروف اور سرگرم بائیں بازو کی رکن کانگریس الیگزینڈریا اوکیشیو کورٹز نے جنوری 2019 میں کہا تھا کہ ایم ایم ٹی کو ہمارے بیانیے کا ایک حصہ قرار پائے جانے کی ضرورت ہے جس کے باعث ایم ایم ٹی کی جانب لوگوں کی توجہ میں مزید اضافہ ہوا۔
کیا دنیا کی سب سے بڑی معیشت ایک بیوقوفانہ معاشی نظریے کے باعث علمی نوعیت کے بحران کا شکار ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو اب کیا کیا جائے؟ یہ بات درست بھی ہے، پاکستان کے معروف ماہر معاشیات بھی چوں کہ اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں اور سرگرم عمل ہیں کہ حکومت اس کے نتائج پیش نظر رکھے۔ یہ صورتحال زیادہ پریشان کن ہے کہ ملک کے صرف ایک ماہر معاشیات ہی اس نظریے کی حمایت میں سردھڑ کی بازی لگانے پر تلے ہوئے ہیں؟ اس میں وزارت خزانہ کا عمل دخل بھی ہے اور ممکن ہے وزارت خزانہ کو اپنی غیر محتاط پالیسیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس علمی محاذ کی ضرورت ہو۔
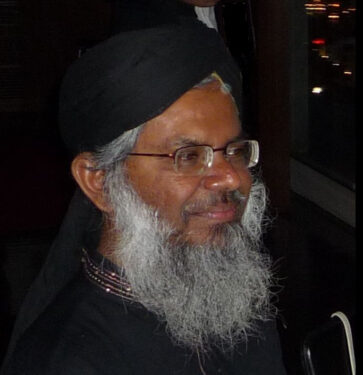
اسد زمان کے لیے مغرب اجنبی نہیں ہے۔ وہ 1971 میں 16 برس کی عمر میں بوسٹن گئے جہاں انہوں نے میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ریاضی میں ماسٹرز کرنے کے بعد سٹینفورڈ یونیورسٹی سے شماریات میں ماسٹرز ڈگری حاصل کرنے کے علاوہ معاشیات میں پی ایچ ڈی بھی کی۔
اسد زمان یونیورسٹی آف پینسلوینیا اور کولمبیا یونیورسٹی میں تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد کسی حد تک مذہب کی جانب راغب ہو گئے اور گزشتہ کچھ برسوں سے پاکستان میں معیشت کے اسلامی پہلوئوں پر بات چیت کر رہے ہیں، وہ مارچ 2019ء تک پانچ سال پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈویلپمنٹ اکنامکس کے وائس چانسلر بھی رہے۔
اسد زمان غیر روایتی نظر آنے یا ایک ایسے تصور پر اٹل یقین رکھنے پر پریشان نہیں ہیں (دنیا میں کچھ ہی ماہرین معاشیات ایسے ہوں گے جو معیشت اور مذہب کا یوں تڑکا لگائیں گے) لیکن اسد زمان اب اسلامی معیشت کا دفاع کرنے کے بجائے سٹیفنی کیلٹن کی طرح ایم ایم ٹی کا دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں۔
اسد زمان نے قریباً پانچ سال قبل اس تصور کے بارے میں پہلی بار سنا تو انہیں یہ ابتدا میں بظاہر بیوقوفانہ لگا تاہم بعد ازاں کسی قدر قابل فہم ہوگیا، اسد زمان نے پرافٹ اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایم ایم ٹی ایک پزل کی طرح بہت سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہے اور اگر ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے الگ کر کے دیکھا جائے تو اس کی کوئی بنیاد نہیں رہتی۔”

اسد زمان نے ایم ایم ٹی پر ہی اپنا پہلا سیمینار مارچ 2019ء میں سٹیٹ بینک آف پاکستان میں منعقد کیا جس میں اس وقت کے گورنر سٹیٹ بینک طارق باجوہ نے بھی شرکت کی۔ (نوٹ: سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے سیمینار کے انعقاد کی اجازت دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایم ایم ٹی کی توثیق کی ہے۔) انہوں نے دوسرے سیمینار کا انعقاد رواں برس کیا جس میں قریباً 60 لوگوں نے شرکت کی۔
کیا یہ پیشرفت پریشان کن ہے؟ لازمی طور پر ایسا نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسی پیشرفت ضرور ہے جس پر بات ہونی چاہئے۔
ایم ایم ٹی دراصل ہے کیا؟
ذرا ماضی کے دریچوں میں جھانکیے جب آپ بچے تھے اور آپ کو والدین کی جانب سے جیب خرچ ملا کرتا تھا۔ آپ لازمی طور پر حیران ہوں گے کہ اگر آپ کو اپنے والدین کی جانب سے ملنے والے ایک مخصوص جیب خرچ پر انحصار نہ کرنا پڑتا تو کیا ہوتا؟ اگر آپ کا جیب خرچ ختم ہی نہ ہوتا یا آپ اس کے بجائے مزید رقم حاصل کرسکتے تو آپ کس قدر زیادہ کھلونے یا آئس کریم خرید سکتے تھے؟
ایم ایم ٹی کا نظریہ بنیادی طور پر اسی سوال کا جواب ہے: تب کوئی سماج یا معیشت کیسی دکھائی دے گی جب اسے رقم کی کوئی رکاوٹ درپیش نہ ہوگی؟ کیا ہی اچھا ہو کہ ناختم ہونے والی دولت کا انبار لگا ہو جسے حکومت استعممال کرسکے۔
اس فلسفیانہ سوال کا جواب دینا کسی حد تک تذبذب کا شکار کر دیتا ہے، چناںچہ ہماری طرح آپ بھی صبر کریں۔ ایم ایم ٹی روایتی فکر کو بنیادی طور پر دو طرح سے درہم برہم کرتی ہے۔
اول، ایم ایم ٹی ہم سے کہتی ہے کہ ہم رقم کے حوالے سے اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ معاشیات کے کسی بھی طالب علم سے سوال کیجئے کہ دولت کیا ہے اور وہ سادہ سا جواب دے گا:روپیہ تبادلے کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو بارٹر سسٹم کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ لیکن حقیقت میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ روپیہ، روپیہ ہے کیوں کہ حکومت کرنسی چھاپتی ہے۔ روپے کی اس لیے قدر نہیں ہے کہ یہ کسی شے کو ظاہر کرتا ہے، روپے کی اس لیے اہمیت ہے کیوں کہ حکومت نے اسے ادائیگی کا ذریعہ تسلیم کر رکھا ہے۔ اس تناظر میں روپیہ درحقیقت ادائیگی کا معیار ہے کیوں کہ حکومت نظام میں روپیہ لا کر روپیہ “بناتی” ہے اور ٹیکس عائد کر کے روپیہ واپس حاصل کرتی ہے۔ یہ امر ناگزیر ہے کہ حکومت ہمیشہ روپیہ خرچ کر کے روپیہ بناتی ہے۔
دوسرا، ایم ایم ٹی میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ حکومتی بجٹ روایتی میکرواکنامک کی ڈگر سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ ایک خاندان یا فرد کچھ بجٹ مخصوص کرتا ہے کہ وہ کس قدر آمدن وصول پا رہا ہے اور اس میں سے وہ کس قدر بچا رہا ہے یا خرچ کر رہا ہے۔ کچھ اسی طرح روایتی طور پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت عوام سے ٹیکس وصول کرتی ہے تاکہ حاصل ہونے والے فنڈز کو مختلف منصوبوں پر خرچ کیا جا سکے۔ اگر حکومت ٹیکسیشن سے حاصل ہونے والی رقم سے زیادہ خرچ کرتی ہے تو خسارے کا شکار ہو جاتی ہے۔
ایم ایم ٹی کے اصولوں کے مطابق حکومت پر بجٹ کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے کیوں کہ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ حکومت روپے کو چھاپنے کی ذمہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت خسارے کا شکار نہیں ہو سکتی اور خسارہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔
فنڈز خرچ کرنے کے لیے ٹیکس بڑَھانے کے بجائے حکومت نے جب فنڈز خرچ کرنا ہوں تو وہ کرنسی چھاپ کر ایسا کر سکتی ہے۔ اس تناظر میں فنڈز بڑھانے کے لیے ٹیکسیشن کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور نظام میں طلب و رسد کی فراوانی کو منتظم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔
کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خسارہ مکمل طور پرغیر متعلق ہے۔ اسد زمان کے مطابق خسارے کی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ حکومت کو خسارہ واپس ادا نہیں کرنا۔ ڈاکٹر زمان کے مطابق، امریکا اس وقت کھربوں ڈالر کے خسارے کا سامنا کر رہا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل ہے۔
یہ جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ نظریہ اس قدر پرکشش کیوں ہے؟ اگر دولت کی رسد پر کوئی حقیقی پابندیاں عائد نہیں ہیں اور خسارہ کوئی معنی نہیں رکھتا تو اس صورت میں امکانات کو ذہن میں لائیے۔ سٹیفنی کیلٹن پر نیویارکر میں شائع ہونے والے مضمون کے مطابق:ایم ایم ٹی کے بلاگز یا ایم ایم ٹی کے ٹویٹر اکائونٹ پر اس نظریے کے حامی ایک ایسی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں جو ایم ایم ٹی کے اصولوں پر قائم ہو جس میں حکومت ملازمتوں کی ضمانت دے، صحت و تعلیم کی سہولیات فراہم کرے اور تباہ حالی کی شکار سڑکوں، ہوائی اڈوں اور پلوں کی جگہ نئے تعمیراتی منصوبے شروع کرے۔
ایم ایم ٹی میں کچھ مستثنیات بھی ہیں۔ ملک نے اپنی کرنسی جاری کرنی ہے۔ چنانچہ امریکا ایم ایم ٹی پر عملدرآمد کر سکتا ہے کیوں کہ وہ ڈالرز پرنٹ کرتا ہے لیکن فرانس میں چونکہ یورو چلتا ہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ (پاکستان ایسا کر سکتا ہے کیوں کہ یہ پاکستانی کرنسی روپیہ جاری کرتا ہے لیکن اس پر مزید بات ہو گی۔)
واکس کے ڈائلن میتھیوز کے مطابق، ایم ایم ٹی کے حامی یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ حکومت کو دیوالیہ نہیں ہونا چاہئے کیوں کہ وہ اپنی کرنسی کے معاملے میں خودمختار ہے: اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روپیہ چھاپتی ہے اور اس روپے پر کنٹرول رکھتی ہے جو یہ ٹیکسوں کی مد میں وصول کرتی ہے اور خرچ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکی حکومت ڈالرز کی کمی کا شکار نہیں ہو سکتی کیوں کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق ڈالر چھاپ سکے۔
اگر رکاوٹ روپے سے متعلق نہیں ہے تو درحقیقت مسئلہ کیا ہے؟ درست، یہ دراصل وسائل کے حوالے سے درپیش ہماری رکاوٹیں ہیں۔
اسد زمان وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں؛” ہم ترقیاتی منصوبوں پر سرمایہ کاری نہیں کرسکتے کیوں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ یہ مکمل طور پر غلط ہے۔ ایم ایم ٹی کے تحت، حکومت ناکافی وسائل یا غیر ترقی یافتہ شعبہ جات پر فنڈز خرچ کر سکتی ہے۔ اضافی فنڈز سے ترقیاتی سرگرمیوں کو بڑھاوا ملے گا اور اضافی طلب پیدا ہو گی جس کے باعث رسد پیدا ہو گی۔

ایم ایم ٹی کا ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ ملازمت فراہم کرنے کی ضمانت دیتی ہے، حکومت کم از کم تنخواہ پر اپنے شہریوں کو ان کے حق کے طور پر ملازمت فراہم کر سکتی ہے۔
چناں چہ خسارہ اہم نہیں ہے، کل وقتی ملازمت ممکن ہے اور روپے کی رسد بڑھ رہی ہے: اس مرحلے پر آپ حیران ہو سکتے ہیں: افراط زر کا کیا ہو گا؟ وہ کیا عوامل ہیں جو ملکوں کو زمبابوے بننے سے روک رہے ہیں؟
ایم ایم ٹی کے نظریے کے مطابق، افراط زر کوئی بہت بڑی ترجیح نہیں ہے۔ افراط زر کا زیادہ تعلق طلب و رسد میں عدم توازن سے ہے۔ سٹیفنی افراط زر کو قابو میں رکھنے پر یقین رکھتی ہیں اور حکومتی اخراجات افراط زر میں اضافے کے بہت زیادہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس کے بجائے، افراط زر کے خطرے سے متعلق درست اندازے مرتب کر کے اور حکومت کے محتاط اخراجات کے ذریعے افراط زر پر قابو پانا ممکن ہو سکتا ہے۔ افراط زر صرف اسی وقت خطرہ بنتا ہے جب ہر شخص کو ملازمت دی جائے (ملازمت دیے جانے کی ضمانت کے باعث) اور اس وقت ٹیکسیشن مددگار ثابت ہوتی ہے۔ فنڈز حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے یہ گردشی فنڈز کی افراط کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
یہ پیش نظر رہے کہ یہاں یہ منطق پیش کی گئی ہے کہ حکومت کو اپنے اخراجات کی ادائیگی کے لیے ٹیکس بڑھانے کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہئے اور اس کے بجائے صرف نوٹ چھاپے جائیں۔ اور اس وقت کیا ہونا چاہئے جب روپوں کی چھپائی افراط زر کا باعث بنے؟ اوہ، لوگوں پر ٹیکس اس لیے عائد کیے جاتے ہیں تاکہ افراط زر پر قابو پانا ممکن ہو سکے۔ درست، اس صورت میں حکومتی اخراجات پورا کرنے کے لیے ٹیکس عائد کرنے میں مسئلہ ہی کیا ہے اور بالخصوص جب افراط زر پیدا ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو؟
شرح سود کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ ایم ایم ٹی کے حامی روایتی ماڈل کو تسلیم نہیں کرتے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ جب خسارہ زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ ایم ایم ٹی ماڈل میں ہے تو حکومت کو زیادہ سے زیادہ قرض لینا پڑتا ہے جس کے باعث شرح سود بڑھ جائے گا۔ اور روایتی طور پر شرح سود میں اضافے میں طلب میں کمی آئے گی۔
لیکن ایم ایم ٹی نظریہ کے حامی اس تعلق کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں اور یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ حقیقت میں طلب کا کسی حد تک شرح سود میں تبدیلی سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ سٹیفنی یہ استدلال پیش کرتی ہیں کہ شرح سود میں کمی کسی پسماندہ آبادی کے لیے غیرموثر ہے جیسا کہ کچھ کاروبار اور صارفین بہت کم شرح سود پر بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔
اور ایم ایم ٹی کے مطابق، بجٹ کا خسارہ درحقیقت شرح سود میں اضافے کا باعث نہیں بنتا۔ حقیقت تو یہ ہے جیسا کہ نیویارک ٹائمز کے ایک مضمون کے مطابق وال سٹریٹ میں بہت سے منیجرز امریکا میں اس کے برعکس بیانیے کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ خسارے میں اضافے کے باوجود تاریخی تناظر میں شرح سود کم رہی ہے۔
چناں چہ ایم ایم ٹی کا مقصد ہی کیا ہے؟ ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ شرح سود کو بھول جائیے کیونکہ ایم ایم ٹی میں شرح سود کو صفر کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کے شرح سود کا ہدف اس تناظر میں بنیادی طور پر غیر متعلق ہے۔
بنیادی طور پر ایم ایم ٹی کے تحت ایک الگ مانیٹری اور مالیاتی پالیسی کے بجائے، آپ کا سامنا محض ایک مالیاتی پالیسی سے ہوتا ہے جس کا ایک اضافی بونس یہ ہے کہ رقم ختم نہیں ہونے جا رہی کیوں کہ آپ ہمیشہ مزید رقم چھاپ سکتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرکزی بینک کو مزید خودمختار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
ذرا ٹھہریے کیوں کہ اس نظریے میں مزید کچھ ایسا ہے جس پر ابھی بات کرنی ہے۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ امریکا میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے لیکن پاکستان میں یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟
پاکستان اور امریکا میں بڑا فرق یہ ہے کہ امریکا ڈالر چھاپتا ہے، وہ اپنی مرضی سے افراط زر میں اضافے کے خدشے کے بغیر ڈالرز چھاپ سکتا ہے اور اسی بنا پر اپنی مرضی کا تجارتی خسارہ برداشت کر سکتا ہے۔ دیگر تمام ملکوں کو اپنے کرنٹ اکائونٹ کی افراط کو پورا کرنے کے لیے ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ درآمدات کے علاوہ زرمبادلہ کے ذخائر کے لیے ڈالرز ہی استعمال ہوتے ہیں۔
جیسا کہ اسد زمان کہتے ہیں، یہ عالمگیریت کا حامل تجارتی نظام ہے جو غیر متناسب ہے جس کے تحت ملکوں کو اپنی برآمدات بڑھانا ہوتی ہیں۔ یہ پاکستان کی طرح کے ملک کے لیے ایک مسئلہ ہے جس کے لیے اپنی برآمدات کو بڑھانا ہمیشہ مشکل رہا ہے۔

اسد زمان کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے لیے یہ سارا نظام ہی نہایت بے ہودہ ہے۔
ایم ایم ٹی کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک محدود نظام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی بیرونی زرمبادلہ میں کوئی ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ ایم ایم ٹی کے تحت چوں کہ پاکستان اپنی کرنسی چھاپنے کے تناظر میں خودمختار ہے اور اسی بنا پر یہ اپنی منشا کے مطابق، روپیہ چھاپ سکتا ہے (اور ایم ایم ٹی کے قانون کے تحت، بینک دیوالیہ نہیں ہوگا). تاہم، حکومت دیگر ملکوں کی کرنسی شائع نہیں کر سکتی اور پاکستان کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا ایک بڑا حصہ ڈالرز پر مشتمل ہے۔
اس وقت آپ غالباً یہ سوچ رہے ہیں کہ ایم ایم ٹی ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن درحقیقت اسد زمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایم ایم ٹی ڈالرز کی کمی کے شکار پاکستان کے لیے اس کے باوجود کچھ حل پیش کرتا ہے۔
برآمدات کو درآمدات سے بڑھانا درحقیقت ممکن نہیں ہے اور بیرونی زرمبادلہ کے ذخائر بھی ایک اہم معاملہ ہیں، ایم ایم ٹی کو کچھ یوں لاگو کیا جائے کہ اس سے توازن خراب نہ ہو۔ اگرچہ اسد زمان کہتے ہیں، پاکستان کے بیرونی زرمبادلہ کے حوالے سے صورت حال زیادہ پریشان کن نہیں ہے۔(اس حقیقت کے باوجود کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی حالیہ سہ ماہی رپورٹ میں حقائق اس کے ) برعکس بیان کیے گئے ہیں۔
سب سے پہلے تو ایکسچینج ریٹ پر قابو پانا ہے۔ اگر حکومت فالتو فنڈز پیدا کرنے میں کامیاب رہتی ہے لیکن ڈالر کی قیمت کم رہتی ہے تو اس صورت میں درآمدات کی طلب میں اضافہ ہو گا اور پاکستان کا ادائیگیوں کا توازن خراب ہو گا۔ اس کے بجائے اگر ڈالر کی قیمت میں اضافہ کیا جاتا ہے اور یہ توازن میں نہیں رہتا تو ڈالرز میں امپورٹ کرنے پر ٹرانسپیئرنٹ ٹیکس عائد کرنا ہوگا۔ درآمدات کا حجم اب بھی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ روپے کی اضافی رسد ہے لیکن ادائیگیوں کا توازن درحقیقت مزید مضبوط ہوگا۔ اگرچہ مختصر دورانیے کے لیے اس کے اثرات منفی ہوں گے لیکن طویل المدتی تناظر میں درآمدات میں کمی آ سکتی ہے۔
دوسرا، خسارے کے اخراجات کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔ ایم ایم ٹی کے تحت خسارہ ادائیگیوں کے توازن کے مسائل پیدا نہیں کرتا تاوقتیکہ یہ ملکی کرنسی ہو۔ اسد زمان چاہتے ہیں کہ حکومت معیشت کے نظرانداز ہونے والے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے. ان کے مطابق، شعبہ تعلیم پر بڑے پیمانے پر فنڈز خرچ کیے جائیں تاکہ انسانی سرمایے کو بہتر بنایا جاسکے۔ نجی شعبہ کی جانب سے 30 برس کے لیے تعلیمی قرضے دیے جائیں اور حکومت ضامن کا کردار ادا کرے۔
اس سے اگلا نکتہ یہ ہے کہ بیرون ملک ملازمت کی ضمانت کی طرح اسد زمان پاکستان کے عوام کو پیداواری ملازمتیں فراہم کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں جس سے ناصرف روزگار کی شرح میں اضافہ ہو گا بلکہ اضافی طلب اور اضافی مصنوعات بھی پیدا ہوں گی۔ یہ ملازمتیں تربیت یافتہ افراد پیدا کریں گی جو اس وقت ایک نظرانداز ہونے والے وسائل میں سے ایک ہیں۔ ان میں کمیونٹی سروسز، بنیادی خواندگی کی فراہمی، شجرکاری، سرسبز بنانے کے منصوبے اور جنگلات کا تحفظ شامل ہے۔
ملازمتوں میں اضافے سے ظاہر ہے، اضافی طلب پیدا ہو گی لیکن یہ اس وقت تک منتظم ہو سکتی ہے جب تک مناسب اضافی وسائل متعلقہ شعبوں کی جانب منتقل کیے جاتے ہیں جہاں اضافی طلب پیدا ہو گی۔ اسد زمان امریکا میں ایم ایم ٹی نظریے کے حامیوں کی طرح افراط زر کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہے۔ متناسب افراط زر پیدا ہوگی جسے خوش آمدید کہا جائے گا، چوں کہ قیمتوں کا میکانزم شروع ہو گا، اضافی طلب کے اثرات رسد پر مرتب ہوں گے۔
ایم ایم ٹی کے ذریعے پاکستان میں سیلف فنانسنگ کے حامل میگا پراجیکٹ حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ زمان کے خیال میں قرضوں سے سڑکوں اور پبلک ورکس کے پروگرام حقیقت بن جائیں گے۔ پاکستان چین کی طرح جدید شہری منصوبہ بندی کے حامل شہر بسائے گا۔ حکومت کا چھوٹے دیہی کاروبار کا منصوبہ اک ہنر اک نگر تیزی سے بڑھ سکتا ہے۔ سیاحت کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے۔
اسد زمان ایم ایم ٹی کے تحت نجی شعبہ کو ترغیب دینے کی تجویز پیش کرتے ہیں۔ موجودہ نظام کے باعث زیادہ شرح سود درحقیقت ترقی کے لیے ایک خطرہ ہے کیوں کہ نجی شعبہ انشورش یا ریئل سٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کو ترجیح دیتا ہے جب کہ حقیقی سرمایہ کاری جس کا متذکرہ بالا سطور میں ذکر ہوا، اسے نظرانداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اسد زمان یہ تجویز دیتے ہیں کہ حکومت نجی شعبہ کو ترغیب دے کہ وہ براہ راست قرضوں کے پروگرام شروع کرے جس کے فوائد طویل المدتی سماجی خوشحالی سے منسلک ہوں۔
مختصرا بات کی جائے تو ایم ایم ٹی پاکستان میں کچھ ایسا دکھائی دے سکتا ہے: ہم یہ امر تسلیم کرتے ہوئے رقم خرچ کر سکتے ہیں کہ ترقیاتی منصوبہ قابل عمل ہے یا نہیں، ہم مستقبل کے ریونیوز سے قرض وصول کر سکتے ہیں اور روپے کو چھاپنے کے علاوہ سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان جب تک اپنے فارن ایکسچینج کی ذمہ داریاں اور ملکی طلب پوری کرسکتا ہے، اسد زمان کہتے ہیں، ایسی صورت میں کیا وجہ ہے کہ یہ ماڈل کام نہ کرے۔
اسد زمان کا ایم ایم ٹی کا ورژن میکرواکنامکس نظریے سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے کیوں کہ یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے خلاف ایک سیاسی نظریہ ہے۔ اسد زمان کے نزدیک ہم ہنوز آئی ایم ایف کے زیراثر ہیں۔ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا کردار یہ یقینی بنانا ہے کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں کو دنیا کے غریب ترین ملک قرضوں کی ادائیگی پر سود ادا کریں۔
اسد زمان کہتے ہیں، آئی ایم ایف کفایت شعاری کا کاروبار ہے اور وہ اسے غریب ملکوں پر نافذ کرتے ہیں تاکہ ان کی معیشت امیر ملکوں کے زیراثر رہے۔اسد زمان کے مطابق، ایم ایم ٹی اس شکنجے سے نکلنے کے لیے راستہ فراہم کر سکتا ہے۔
کیا آپ اب بھی پریقین نہیں ہیں؟ یہ لوگ بھی پریقین نہیں ہیں
استعماری نظریات سے قطع نظر لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اس نظریے سے اختلافات ہیں جن میں امریکی لبرل میکرو اکانومسٹ اور نوبیل انعام یافتہ پال کروگمین، فیڈرل ریزروز کے سربراہ جیروم پائول، کھرب پتی بل گیٹس اور آئی ایم ایف کے سابق چیف اکانومسٹ کینیتھ روگوف شامل ہیں۔
گزشتہ برس دسمبر میں ہی رجعت پسند امریکی ماہر معاشیات گریگوری مانکیو نے ایک مقابلہ بعنوان ماڈرن مانیٹری تھیوری کے حوالے سے شکوک و شبہات پر مبنی ایک گائیڈ شائع کی۔ یہ اس تمہید کے ساتھ شروع ہوتی ہے:اس پروفیشن میں چالیس برس گزارنے کے بعد، میں مکمل طور پر مرکزی دھارے کی میکرواکنامکس کے زیراثر ہوں کہ ایم ایم ٹی کی کھل کر تعریف کر سکوں۔ لیکن وہ اس کے باوجود کوشش کرتے ہیں۔
اول، وہ اس مفروضے پر سوال کرتے ہیں کہ ایم ایم ٹی کے تحت حکومتی قرضے کے حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مانیٹری کی بنیاد میں اضافے سے بینکوں کی جانب سے قرض دیے جانے اور رقم کی رسد میں اضافہ ہو گا جس سے مہنگائی غیر معمولی طور پر بڑھے گی۔ مقالے میں مزید لکھا گیا ہے، ان حالات کے باعث حکومت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ زیادہ روپیہ چھاپنے کے بجائے دیوالیہ ہونا بہتر ہے۔ حکومت اس لیے دیوالیہ ہونے کا فیصلہ نہیں کرے گی کیوں کہ یہ ناگزیر ہے بلکہ مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند رکھنے کے لیے ایسا کرنا ناگزیر ہے۔
وہ ایم ایم ٹی کے مفروضے پر بھی سوال پوچھتے ہیں کہ افراط زر اور روپے کی رسد میں اضافے کے درمیان زیادہ تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے، کہ یہ دعوی اس معاملے کو مرکزی دھارے کی فکر کے مقابل مبالغہ آمیزی کا روپ دیتا ہے۔ امریکا میں 1870 سے اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق، ڈالرز کی چھپائی اور افراط زر میں تعلق 0.79 فی صد رہا ہے۔
وہ افراط زر کے بارے میں بھی وضاحت کرتے ہیں:افراط زر میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب آئوٹ پٹ اور روزگار اپنی فطری سطح سے بڑھ جائے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ قیمتوں کے تعین کے ذمہ دار سماجی بہبود کو بڑھانے کا عزم نہیں رکھتے، وہ محض منافعوں کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایم ایم ٹی کے ماہرین معاشیات قیمتوں کے تعین کے حوالے سے حکومتی ہدایت نامے یا پرائس کنٹرولز کو استعمال میں لاکر یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ لیکن منکیو استدلال پیش کرتے ہیں؛ معاشیات کی پیچیدگی اور قیمتوں کو قابو میں رکھنے کی تاریخ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حل قابل عمل نہیں ہے۔
یہ اصول پاکستان پر بھی لاگو ہو سکتا ہے: جیسا کہ اسد زمان کہتے ہیں کہ ہم خود کو مناسب طور پر افراط زر اور غیرملکی زرمبادلہ کے ذخائر کو بڑھنے سے مناسب طور پر روک سکتے ہیں اور روپے کو تذوراتی طور پر خرچ کر سکتے ہیں۔۔۔ کیا یہ طریقہ کار عملی ہو گا؟ کیا پاکستانی حکومت کے پاس اس قدر وسائل ہیں کہ وہ اس نوعیت کی معیشت کو منتظم کر سکے یا نجی شعبہ کو ترغیب دینے کے لیے اس کی منشا کے مطابق قوانین بنائے؟
امریکا میں مقیم ایک پاکستانی ماہر معاشیات نے اسد زمان کے احترام میں نام ظاہر نہ کرنے کی خواہش پر پرافٹ کو دو صفحات پر مشتمل تردیدی بیان ارسال کیا جس میں انہوں نے اس نظریے کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان میں ایم ایم ٹی کے بارے میں کہا، یہ قطعی طور پر ایک ڈرائونا خواب ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جنوبی ایشیا اور بالخصوص پاکستان میں مرکزی بینکوں پر سیاست کا بہت گہرا اثر ہے۔

انہوں نے لکھا:مرکزی بینکوں کے ہمارے گورنرز باقاعدہ طریقہ کار اختیار کیے بغیر تعینات کیے جاتے ہیں اور نکال دیے جاتے ہیں، وہ تاریخی تناظر میں نان مانیٹری ماہر معاشیات ہیں جیساکہ ریزرو بینک آف انڈیا میں راگھو (رام راجہ) اور ارجیت (پاٹیل) ان ایشوز کی بہترین مثالیں ہیں۔ ہم پہلے ہی متعدد بار ڈبل ڈجٹ میں افراط زر کا سامنا کر چکے ہیں جس کی وجہ مانیٹری پالیسی پر سیاسی اثر و رسوخ ہے۔ مرکزی بینک کو کرنسی چھاپنے کی اجازت دینا اس صورت حال کو مزید خراب کرنے جا رہا ہے۔
ایم ایم ٹی کا ایک اہم نکتہ نظرانداز ہونے والے وسائل ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ درست ہے کہ پاکستانی معیشت میں بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ لیکن کیا مانیٹری پالیسی اس کی پیداواری صلاحیت میں رکاوٹ ہے؟ غالباً ایسا نہیں ہے، یہ نکتہ پیش نظر رہے کہ معیشت کا ایک بڑا حصہ مشکلات کا شکار ہے۔ ہماری پیداواری صلاحیت کے کم ہونے کی وجہ غالباً بہت سی رکاوٹیں ہیں جن میں معاشی منڈیوں تک رسائی حاصل نہ کر پانا(جیسا کہ مستقبل کی منڈی تک رسائی کا نہ ہونا)، لیبرفورس میں خواتین کی قلت اور ایسے ہی دیگر مسائل درپیش ہیں۔
آگے کیا کیا جائے؟
یہ واضح رہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کسی بھی مرحلے پر میکرواکنامکس کے حوالے سے اس نوعیت کی بنیاد پرست حکمت عملی کی حمایت نہیں کی۔ ظاہر ہے، ہم اسے نافذ نہیں کر سکتے گو اگر ہم ایسا چاہتے بھی ہیں، آئی ایم ایف کی بیل ائوٹ شرائط کے ساتھ کیا کیا جائے؟ لیکن یہ تصور شدید ترین مزاحمت کے باوجود اب بھی موجود ہے۔ سٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایم ایم ٹی سیمینار کے اختتام پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کے بہت سے ارکان تذبذب کا شکار نظر آئے اور انہوں نے اسد زمان سے سوالات پوچھے۔ بہت سوں کی توجہ اسی نکتے پر مرکوز رہی جو مہنگائی یا بہت زیادہ مہنگائی سے متعلق تھا اور بالخصوص یہ پاکستان میں فوڈ سپلائز سے متعلق تھا۔
اسد زمان سے جب ایم ایم ٹی پر ہونے والی تنقید پر بات کی گئی تو وہ مسکرا دیے اور کہا، یہ تنقید لازمی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ قدرے نیا تصور ہے، آپ کو تجربے کرنے کے لیے تیار ہونا چاہئے۔ وہ مختلف طرز فکر کے حامل ماہر معاشیات ہیں، وہ غالباً تنقید سننے کے عادی ہیں جس کی ایک وجہ ان کا مذہب کی جانب جھکائو بھی ہے، وہ ایم ایم ٹی کا دفاع اچھائی اور برائی میں جنگ کے طور پر کرتے ہیں۔
اسد زمان کے لیے ان کا پختہ اور راسخ عقیدہ ان کی شخصیت کے مطابق ہے۔ لیکن اس نظریے کے پاکستان کے تناظر میں مضمرات سے نظریں چڑانا ممکن نہیں۔